اردو دنیا، مارچ 2025
دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں میں تنقید نے علم و ادب
کی ایک اہم شاخ اور ایک علیحدہ فن کی حیثیت سے اپنی جگہ پیدا کرلی ہے۔ ادب کا کوئی
سنجیدہ طالب علم جو ادب کو محض تفریح، دل بہلاوے اور وقت گزاری کی چیز نہیں سمجھتا
بلکہ اسے انسانی تہذیب و تمدن کے اعلیٰ ترین مظاہر میں شمار کرتا ہے، وہ تنقید سے
بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانے تک یہ خیال عام تھا اور بعض لوگ اب بھی اسی طرح
سوچتے ہیں کہ شعر و ادب کی تخلیق ایک پراسرار الہامی قوت کے زیراثر ہوتی ہے جو عقل
و شعور کی گرفت سے باہر ہے، اس پر منطق و استدلال کا حربہ استعمال کرنا اس کی
لطافت کو زائل کرنا ہے، ادب کو ایک زمانے تک جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی قسم کی چیز
سمجھا جاتا تھا۔ شاعروں کو تلامیذ الرحمن کہا گیا۔ عربی زبان کی کہاوت تھی ’الشاعر
کالمجنون‘ مجنون کے لفظی معنی وہ شخص جس پر جنون کا سایہ ہو۔ انسانی علم نے جہاں
کائنات کے اور سربستہ رازوں کا پردہ فاش کیا اور فطرت کے بے شمار عقدوں کو حل کیا
وہاں شعر و ادب کے پیچیدہ تخلیقی عمل کی گرہیں بھی کھولیں اور اسے اپنے شعور کے
تابع کرنے کی کوشش کی۔ ادب زندگی کی عکاسی یا آئینہ داری کرتا ہے یا ادب کا مقصد
تنقید حیات ہے اس قسم کے فقرے اب اس قدر پیش پا افتادہ ہوچکے ہیں جس طرح یہ کہنا
کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے
کہ جب کہنے والے نے پہلی بار یہ بات کہی تھی تو اسے اپنے زمانے کا بہت بڑا باغی
کہا گیا اور اس کے اس خیال کو کفر و الحاد سے تعبیر کرکے اسے پھانسی پر لٹکایا گیا۔
ادب اور مادی زندگی کے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش، مادی
زندگی ہی کی طرح ادب کو بھی جامد اور اٹل ماننے کے بجائے متحرک اور ارتقا پذیر
سمجھنا، مادی زندگی ہی کی طرح ادب میں مثبت و منفی قوتوں کے تصادم و پیکار کے جدلیاتی
عمل کو پہچاننے اور اس سے شعوری طور پر عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی فہم و بصیرت کو
استعمال کرنے کا نام تنقید ہے۔ مڈلٹن مرے کہتا ہے کہ:
’’جس
طرح زندگی کا شعور و احساس فن ہے اسی طرح فن کا شعور و احساس تنقید ہے۔‘‘
یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر شعر و ادب محض تک بندی یا
قافیہ پیمائی، محض لفظی بازی گری، ذہنی عیاشی یا بیکاری کا مشعلہ نہیں ہے بلکہ یہ
ایک باحواس اور سنجیدہ عمل ہے، تو ہر تخلیقی عمل کے ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی کام
کرتا ہے اور سب سے پہلے خود شاعر اور ادیب کی اپنی ذات میں ایک نقاد چھپا بیٹھا
رہتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نظم یا نثر کی کوئی تصنیف جب وجود میں
آتی ہے، تو وجود میں آنے سے قبل مختلف مراحل سے گزرتی ہے، لکھنے والا ایک موضوع
منتخب کرتاہے، زندگی کے بے شمار مظاہر، احساسات اور تجربات میں سے چند کو چنتا ہے،
پھر ان کی ترکیب و تعمیر کرتا ہے، ان میں ترمیم و تنسیخ، حک و اصلاح اور تراش خراش
کرتا رہتا ہے۔ اپنے مسودے کو بار بار دیکھتا اور اسے ایک خاص معیار اور سطح پر
لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنی ہی عرق ریزیوں اور جانفشانیوں کے بعد یہ تحریر اس قابل
ہوتی ہے کہ خود فنکار کا دل اس سے مطمئن ہو۔ اس کا کہنا ہے ادیب کا یہ تمام عمل اس
کے تنقیدی شعور کا ثبوت ہے۔ اسی لیے بار بار اس نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اعلیٰ
وقیع، زندہ اور پائیدار ادب کی تخلیق وہی ادیب کرسکتا ہے جو اعلیٰ درجے کے تنقیدی
شعور کا بھی مالک ہو۔ خود رو ادیب و شاعر جنھیں زندگی سے کوئی سنجیدہ لگاؤ نہیں،
جو مظاہر حیات کی پرکھ یا بصیرت نہیں رکھتے اور نہ جنھیں اپنے تجربات و احساسات کی
تعمیر و تنظیم کا سلیقہ اور ہنر آتا ہے اور نہ ہی وہ اس ہنر کے لیے مشقت و ریاضت
کرتے ہیں، ان کا ادب بھی ویسا ہی حقیر، ناکارہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ مختلف
زبانوں کے تنقیدی ادب کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ بات چھپی نہیں کہ ادبی
تنقید کا ایک خاصا بڑا حصہ ان لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے جو خود بھی تخلیقی ادیب
تھے۔ انھوں نے اپنے مضامین، خطبوں، دیباچوں اور خطوں میں ادبی تخلیق کے متعلق جو
بصیرت افروز رائیں دیں یا اپنے تجربات بیان کیے ہیں ان سے شعر و ادب کے ارتقا میں
بڑی مدد ملی ہے۔ اسپنسر، ڈرائیڈن، کولرج، ورڈزورتھ، میتھیوآرنلڈ، شیلی، ہیزلٹ،
گوئٹے، ایڈگر ایلن پو، ٹی، ایس ایلیٹ، ایذرا پاؤنڈ، سی ڈے لیوس، جے بی پریسلے، ای
ایم فارسٹر، سامرسٹ مآم، سارترمے، ٹیگور اور اردو میں حالی سامنے کے نام ہیں۔
یہاں آکر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہی دراصل فساد کی
جڑ بھی ہے کہ جو شخص خود ادیب و شاعر ہے، جسے شعر، افسانہ، ناول، ڈرامہ یا کسی اور
تخلیقی صنف ادب کا ذاتی تجربہ ہے اس پر تو بھروسہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے تنقیدی
خیالات کو قابل اعتنا سمجھا جاسکتا ہے لیکن جو شخص خود ادب کی تخلیق نہیں کرتا اور
نہ اسے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ایک تخلیقی فنکار گزرتا ہے وہ کیسے
ان مسائل کو سمجھ سکتا اور ان پر کوئی حکم لگا سکتا ہے۔ اس طرح کا سوال اٹھانے
والے ایسے ادیب کے وجود کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ’نقاد محض‘ ہے بلکہ
بعض لوگ تو ایسے نقادوں کو ادیب ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک
ایسی مخلوق ہے جو ادب میں بے جا مداخلت کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادبی تخلیق
کا اپنے آپ کو اہل نہ پاکر یا ادب کے میدان میں ناکام ہوکر تنقید کی طرف رخ کرتے
ہیں۔ ان کی حیثیت طفیلی کی سی ہے۔ یہ ادیبوں کے بل بوتے پر نام کمانا چاہتے ہیں۔ یہ
لوگ یا تو کسی کی مدح سرائی کرتے ہیں اور ان کی تخلیقات کو مقبول بنانے کے لیے ایسے
مضامین لکھتے ہیں جن سے ان کے ممدوح کا اشتہار ہو یا کسی کی نکتہ چینی اور مخالفت
کرکے اس کے کارناموں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی تصور کے ماتحت بہت سے ادیبوں
نے نقادوں کے نام پر لعنت بھیجی ہے۔ کسی نے انھیں ادبی جونک کہا، کسی نے انھیں ان
مکھیوں سے تشبیہ دی جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھتی، انھیں پریشان کرتی اور کام کرنے سے
روکتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک نقاد کا وجود ادب کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔
اس سے پہلے کہ ہم نقاد محض کے متعلق کچھ اور کہیں، یہ
بتا دینا ضروری ہے کہ تنقید کے نام پر لکھی ہوئی ہر تحریر شاعری یا ادب نہیں کہی
جاسکتی۔ شاعری جب اپنے منصب سے گر جاتی ہے تو محض کلام موزوں ہوکر رہ جاتی ہے یا
لفظوں کا کرتب، افسانہ اور ناول جب اپنے منصب سے گر جاتا ہے تو محض نثر کا ایک بے
جان ٹکڑا ہوتا ہے یا پھر پمفلٹ بازی، کوک شاستر اور محض دل لگی کی چیز، اسی طرح
تنقید جب اپنے منصب سے گر جاتی ہے تو مدح سرائی پروپیگنڈہ نکتہ چینی، تنقیص اور
خوردہ گیری ہوکر رہ جاتی ہے۔ جس طرح
شاعروں میں متشاعر اور ادیبوں میں جعلی ادیب ہوسکتے ہیں، اسی طرح نقادوں کی صف میں
بھی مفتی و مبلغ اور ادبی بہروپیے مل سکتے ہیں۔ جہاں تک نکتہ چینی، مخالفت اور کسی
ادیب کی ادبی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے کا سوال ہے وہ ہمیشہ نقاد محض ہی کی جانب سے
نہیں ہوتی۔ خود شاعروں، ادیبوں اور تخلیقی فنکاروں میں معاصرانہ چشمکیں رہی ہیں۔ یہ
اختلافات کبھی تو فنی اور دبستانی ہوتے ہیں اور کبھی ذاتی۔ اردو ادب کا ہر طالب
علم میر و سودا، انشا و مصحفی، آتش و ناسخ، انیس و دبیر، غالب و ذوق اور امیر و
داغ کے ادبی معرکوں اور ان کی معاصرانہ رقابتوں اور چشمکوں سے واقف ہے۔ ان جھگڑوں
میں کس بے چارے نقاد کا ہاتھ تھا۔
اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جو شخص خود ادیب و شاعر نہیں وہ
ادب کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور کس طرح اس کے کھرے کھوٹے کو پرکھ سکتا ہے۔
اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فن لطیف کی طرح وہی شخص مائل ہوتا ہے جو
خود بھی حس لطیف رکھتا ہو، ابن رشیق کے قول کے مطابق ایسا شخص بھی اپنے اندر تخلیقی
جوہر رکھتا ہے۔ ادب کے قاری کے اندر اگر یہ حس لطیف اور تخلیقی جوہر نہ ہو تو اس
کے لیے ادب بے مصرف چیز ہے۔ یہ حس اور جوہر بھی جامد اور اٹل نہیں بلکہ متحرک اور
ترقی پذیر ہے اور اس میں برابر نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ پہلے زمانے میں شاعر کے لیے
یہ لازمی شرط تھی کہ وہ پیدائشی موزونیت پر ہی قناعت نہ کرے بلکہ اچھے شعرا کے
کلام کا مطالعہ کرتا رہے اور اس سے پورے طور پر لطف اندوز ہوتا کہ اس کی حس لطیف
اور اس کے اندر کے تخلیقی جوہر جلا پاتے رہیں۔ پرانے اساتذہ کسی شاعر کو اس وقت تک
شاگرد بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے جب تک اسے منتخب اور بہترین اشعار خاصی
تعداد میں یاد نہ ہوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب تک اس کے ذہن کی اس طور پر تربیت
نہ ہو اسے شاعرانہ اور غیرشاعرانہ کلام کا فرق نہیں معلوم ہوسکتا۔
یہ حس لطیف اور تخلیقی جوہر ہی وہ مشترک چیز ہے جس کی
بنا پر شعر یا ادب پارہ اپنے اندر ایک وسیع اور عالمگیر حلقۂ اثر رکھتا ہے۔ اگر ایسا
نہ ہوتا تو شاعر خود شعر کہتا اور اس سے لطف اندوز ہوتا، ناول، افسانہ، ڈرامہ یا
ادب کا کوئی اور نمونہ ناول نگار یا ادیب کے علاوہ دوسرے شخص کے لیے کوئی معنی نہ
رکھتا۔ یہی نہیں بلکہ ایک شاعر کا شعر دوسرے شاعر کے لیے اور ایک ادیب کی تحریر
دوسرے ادیب کے لیے بیکار ہوتی۔ شاعر نثر سے لطف نہ اٹھا سکتا اور نثرنگار کے لیے
شعر میں کوئی جاذبیت نہ ہوتی۔ کالیداس، ہومر، شیکسپیئر، فردوسی اور بالمیکی جنھوں
نے ہزاروں برس پہلے اپنے تجربات و مشاہدات کا اظہار کیا۔ آج کے انسان کے لیے کسی
قسم کی دلکشی نہ رکھتے۔ ادیب اور نقاد میں اسی قسم کا فرق ہے جس طرح کا فرق شاعر
اور نثر نگار میں ہوتا ہے۔ شاعر اور نثر نگار دونوں تخلیقی جوہر رکھتے ہیں لیکن ان
کی افتاد طبع مختلف ہوتی ہے۔ شاعر میں تخیل اور جذبے کا عنصر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے
اور وہ تخیلی اور ترکیبی ذہن رکھتا ہے۔ نثر نگار میں عقل و استدلال کا عنصر نسبتاً
حاوی ہوتا ہے اور اس کا ذہن تعمیری اور تجزیاتی ہوتا ہے۔ دونوں تخلیقی ذہن رکھتے ہیں
لیکن افتاد طبع مختلف ہونے کی وجہ سے اپنے تجربات و احساسات کے اظہار کے لیے مختلف
پیرایۂ بیان اختیار کرتے ہیں۔ انھیں عناصر کی کمی بیشی سے خود شاعر اور نثر نگار
کی تخلیقات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ شاعر پر جب تخیل اور جذبے کی گرفت مضبوط نہیں
ہوتی تو اس کا کلام موزوں ہونے کے باوجود نثر کی سرحد میں داخل ہوجاتا ہے اور نثر
نگار پر جب تخیل اور جذبے کا غلبہ ہوجاتا ہے اور عقل و استدلال کا دامن اس کے ہاتھ
سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی نثر شاعرانہ ہوجاتی ہے۔ پھر شاعر اور نثر نگار تخلیقی
جوہر رکھنے کے باوجود چوبیس گھنٹے شاعر اور ادیب نہیں ہوتے۔ تخلیقی جوہر عام طور
پر دبا ہوا یا سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب پورے طور پر بیدار ہوتا ہے تو ادب پارہ
وجود میںا ٓتا ہے۔ یا کوئی شعر یا نثری تحریر مکمل تخلیق بنتی ہے۔ اگر ایسا نہ
ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ شاعر کا ہر شعر یکساں نہیں ہوتا، اور نثر نگار کی ہر تحریر
اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتی۔ کیا وجہ ہے کہ بعض شاعر آخر عمر تک شعر نہیں کہہ
پاتے، ایک خاص منزل پر پہنچ کر ان پر شعر نازل نہیں ہوتا یا ان کی شاعری انحطاط پذیر
ہوجاتی ہے اس طرح ایک ادیب اپنی زندگی میں چند شاہکار لکھنے کے بعد خاموش ہوجاتا
ہے یا پھر اس طرح کی تخلیق پر قادر نہیں ہوتا۔
یہ بات معلوم ہوجانے کے بعد کہ تخلیقی جوہر اور حس لطیف
شاعر اور نثر نگاردونوں میں مشترک ہے اور افتاد طبع کا فرق ان کے لیے مختلف پیرایۂ
بیان اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم عام نثرنگار اور نقاد کو دیکھیں تو
اندازہ ہوگا کہ دونوں بعض مشترک عناصر رکھتے ہیں اور بعض اعتبار سے دونوں کی شخصیتوں
میں فرق ہوتا ہے۔ عام ادیب یا نثر نگار زندگی کا شعور و احساس رکھتا ہے اور اس
شعور و احساس کو ایک تخلیقی پیکر میں ڈھالتا ہے۔ نقاد بھی زندگی کا شعور و احساس
رکھتا ہے لیکن اس شعور و احساس کو کسی تخلیقی پیکر میں براہ راست منتقل کرنے کے
بجائے کسی تخلیقی پیکر اور زندگی کے شعور و احساس میں جو پیچیدہ رشتہ ہے اس کی نوعیت
اور ماہیت کا ادراک کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ادراک بھی ایک طرح کا تخلیقی عمل ہے، اور اس کے وسیلے سے جو ایک نئی تخلیق
وجود میں آتی ہے اس میں لکھنے والے کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ
درجے کی تنقید بھی اعلیٰ درجے کی تخلیقی نثر ہوتی ہے اور ہر اچھا تنقید نگار اچھا
نثر نگار بھی ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر اور ادیب کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور وہ چند
تصورات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ زندگی کے مظاہر سے دلچسپی رکھتا
اور اس کے متعلق اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح تنقید نگار بھی اپنی شخصیت
اور اپنا زاویۂ نظر بھی رکھتا ہے۔ جس طرح ادیبوں اور شاعروں میں طرح طرح کے ادیب
اور شاعر ہیں یعنی کوئی مذہب و اخلاق کی طرف مائل ہے، کوئی حسن و محبت سے دلچسپی
رکھتا ہے، کسی کے یہاں نشاطیہ عنصر غالب ہے اور کسی کے یہاں حزینہ، کوئی رجائی ہے
تو کوئی قنوطی، کوئی عینیت پسند اور رومانی ہے تو کوئی حقیقت پسند اور واقعیت کا
دلدادہ، کوئی رنگینی پر فدا ہے تو کسی کا سادگی پر ایمان ہے کسی کو اجتماعیت کا غم
ستاتا ہے تو کوئی انفرادیت کا اسیر ہے، کوئی سیاست کو قدر اعلیٰ سمجھتا ہے تو کوئی
جنس کو، غرض شاعری اور ادب میں شخصیتوں کے فرق سے جو رنگارنگی اور بوقلمونی ہے وہی
رنگارنگی اور بوقلمونی نقادوں میں بھی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید کے بھی بے
شمار دبستان ہیں، رومانی تنقید، داخلی تنقید، جمالیاتی تنقید، تاثراتی تنقید،
اخلاقی تنقید، تاریخی تنقید، وجدانی تنقید، نفسیاتی تنقید، سماجی تنقید، عمرانی
تنقید، مارکسی تنقید، لسانی تنقید، فنی تنقید اور اس طرح کی بہت سی اصطلاحیں عام
ہوچکی ہیں۔ ہر تنقید کے اپنے حدود ہیں اور اسی اعتبار سے وہ مفید یا غیرمفید ہوسکتی
ہے۔ مختلف دبستانوں کے ادیب و نقاد اپنی تنقید کو جامع اور معتبر اور دوسری قسم کی
تنقید کو غلط کہتے ہیں۔
ادبی دبستانوں کی طرح تنقیدی دبستانوں میں بھی آویزش و
پیکار رہی ہے، اسی لیے موجودہ زمانے میں
بعض لوگوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کی تنقید ہو جو ہر زمانے کے ادب کو
اور ہر نوعیت کے ادیب کو پرکھنے، اس سے لطف اندوز ہونے اور اس کی ادبی قدر و قیمت
متعین کرنے میں کام آسکے۔ جو ہر طرح مکمل، جامع اور ہمہ گیر ہو، جو کسی نوعیت کے
ادب کی نہ بے جا طرفداری اور وکالت کرے اور نہ
اس کے ساتھ بے انصافی برتے۔ ایسے ادیبوں کا خیال ہے کہ وہی تنقید صحیح
معنوں میں تنقید ہوگی اور اسے ادبی تنقید یا سائنٹفک تنقید کہہ سکیں گے۔ اس خیال
کا علمبردار آئی، اے رچرڈس ہے۔ رچرڈس کا کہنا ہے کہ تنقید کا سب سے پہلا فریضہ یہ
ہے کہ وہ ادبی قدروں کا تعین کرے۔ مختلف زمانے کے ادبی شاہکاروں کا مطالعہ کرکے سب
سے پہلے یہ بات طے کی جائے کہ کون سی چیز ادب ہے اور کون سی چیز ادب نہیں ہے۔ پھر
مختلف اصناف، اسالیب، ہیئتوں، اور اظہار کے پیرایوں کی ساخت، ان کی نوعیت، ان میں
تبدیلی اور ارتقا کے عمل کو سمجھا جائے اور ان کا اس طرح تجزیہ کیا جائے کہ کچھ
واضح اصول متعین ہوسکیں۔ اس نظریے کے مطابق وہ نقاد سے بہت سے مطالبے کرتا ہے اور
اس کا خیال ہے کہ ادیب بننا نسبتاً سہل ہے لیکن نقاد بننا مشکل، اس لیے کہ ادیب ایک
خاص موضوع، ایک خاص نظریہ زندگی کے ایک یا چند تجربات، ایک مخصوص اسلوب ہیئت یا پیرایۂ
اظہار کے حدود یا دائرے میں رہ کر کامیاب
ادب کی تخلیق کرسکتا ہے کیونکہ اس کی ذمے داری بس اتنی ہے کہ وہ اپنے مواد کو تخلیقی
مراحل سے گزار کر ایک مناسب صورت میں منتقل کردے لیکن نقاد کو ان حدود اور دائروں
سے نکل کر ہر طرح کے ادب، ہر طرح کے اسلوب،
ہر طرح کے نظریے اور ہر زمانے کی تاریخ او رہر دور کی تہذیب و معاشرت اور
اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ پھر ادب کے عالمگیر اصولوں کے علاوہ اپنی زبان کے مخصوص
مزاج، اس کے اسالیب کی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے عوامل و محرکات کا پتہ لگانے کی
ضرورت ہے، ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی ایک نقاد اخلاقی، نظریاتی یا صنفی اور
تکنیکی تعصبات سے بلند ہوکر ادبی کارناموں کی قدر و قیمت متعین کرنے کا اہل ہوسکتا
ہے۔ اردو میں اس طرح کی سائنٹفک تنقید کے علمبردار کلیم الدین احمد ہیں، جنھوں نے
اپنی کتاب ’اردو تنقید پر ایک نظر کا آغاز ان فقروں سے کیا ہے کہ اردو میں تنقید
کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر ؎
صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے
کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے
یا
جغرافیۂ وجود سارا
ہر چند کہ ہم نے چھان مارا
کی سیر بھی گرچہ بحر و بر کی
لیکن نہ خبر ملی کمر کی
اسی طرح نگاہِ جستجو جغرافیۂ اردو کی سیر کرکے مایوس
واپس آتی ہے لیکن تنقید کے جلوے سے مسرور نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اردو میں تنقید کا
وجود ہی نہیں تو پھر اردو تنقید پر کئی سو صفحوں کی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض زیادہ وزنی نہیں اس لیے کہ کلیم الدین کا خیال ہے کہ
تنقید کے نام پر جو کچھ لکھا جاتا رہاہے یا اب تک اس کے جو دبستاں ہمارے یہاں مروج
رہے ہیں وہ محدود معنوں میں ہی تنقید کہے جاسکتے ہیں۔ صحیح یا سائنٹفک تنقید جیسی
وہ چاہتے ہیں کچھ اور ہی نوعیت کی ہوگی اور اسی کو ادبی تنقید کہہ سکیں گے۔ یہ ایک
علیحدہ مسئلہ ہے کہ خود کلیم الدین بھی اس نوع کی تنقید کے اہل نظر نہیںا ٓتے جس
کا سب سے بڑا ثبوت ان کی کتاب ’اردو شاعری پر ایک نظر‘ ہے جس میں اردو شاعروں پر
لکھتے ہوئے انھوں نے اردو زبان کے مزاج، اس کی تاریخی تبدیلیوں اور اردو شاعری کی
اصناف کے عوامل اور محرکات کا کچھ لحاظ نہیں رکھا، ان کے اندر اس حس لطیف کی بھی
کمی ہے، جو ہر ادیب اور نقاد کے لیے شرط اولین ہے۔ البتہ اردو کے تنقیدی سرمائے کے
بارے میں جو بات انھوں نے کہی ہے اس میں ورڈس کے خیالات کی ہی بازگشت ہے۔ رچرڈس نے
اپنی کتاب ’ادبی تنقید کے اصول’‘ میں ساری دنیا کی تنقید پر یہی رائے دی ہے۔ وہ
لکھتا ہے:
’’کچھ
اٹکل پچو باتیں کچھ پند و نصائح کچھ بے ربط خیالات ، بھڑکیلے اقتباسات، شاعرانہ
لفاظی اور قیاس آرائی زیادہ تر مفروضات اور کہیں کہیں سچے خیالات، کہیں تشریح و
توضیح، کہیں تبلیغ و اشتہار اور کہیں نکتہ چینی اور حرف گیری، بس اسی قسم کی کچھ چیزیں
ہیں جن کے مجموعے کا نام تنقید ہے۔‘‘
رچرڈس نے جس معیاری اور مثالی تنقید کا تصور پیش کیا ہے
وہ خود انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں میں محض ایک خوش آئند خواب کی حیثیت
رکھتی ہے اور اردو میں تو اس طرح کے نقادوں کی آمد ابھی بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ اردو میں رہی سہی
جو بھی تنقید تھی وہ اس وقت ایک بحرانی
دور سے گزر رہی ہے۔
یہاں سے گفتگو اس موڑ پر آپہنچی ہے جہاں زبان
کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن کیا کیجیے
کہے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ محض ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہوتا تو کوئی
بات نہ تھی لیکن اس مسئلے سے خود اردو ادب کی بقا اور اس کی آئندہ ترقی کا سوال
وابستہ ہے۔ کلیم الدین کے نزدیک اردو تنقید ناقص اور یک طرفہ سہی لیکن حالی سے لے
کر اب تک اردو ادب کی جو سمت اور رفتار رہی ہے اس میں جو پیچ و خم اور جو موڑ آئے
ہیں اس کا تعلق ہماری تنقید سے بہت گہرا ہے۔ سرسید اور حالی سے پہلے اردو زبان نے
ہمیں بعض اعلیٰ درجے کے شاعر دیے ہیں جن پر ہم بجا طور پر فخر کرسکتے ہیں لیکن اس
سے پہلے کی ادبی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے
یہاں خود رو قسم کے شاعر زیادہ تھے، ہماری شاعری ایک جنگل تھی جہاں جھاڑ جھنکاڑ کی
بہتات ہوتی ہے۔ درباری ماحول اور انحطاط پذیر معاشرے میں رہ کر شاعری دن بہ دن
زوال آمادہ ہوتی جارہی تھی۔ اس کا مقصد محض لفظی الٹ پھیر اور تک بند تھی یا سستے
قسم کے جذبات کی تسکین، اس میں زندگی سے گریز اور تصنع کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ حقیقی
شاعروں کے مقابلے میں جعلی شاعروں اور استادوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اس ماحول
میں مصحفی نے انشا کے آگے سپر ڈال دی۔ نہ ناسخ کے مقابلے میں آتش کا سکہ چلا اور
نہ ذوق کے آگے غالب کا چراغ جل سکا۔ غدر کے بعد ہمارے یہاں نئی تعلیم اور نئی تہذیب
آئی، اس کے ذریعے جو نیا شعور آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا اس کے نزدیک شاعری
کی کوئی وقعت نہیں رہ گئی تھی۔ ناکاروں کا ایک مشغلہ جو بے عمل بھی بناتا ہے اور
اخلاق و کردار پر برا اثر ڈالتا ہے۔ نذیرا حمد کے ناولوں میں شعرا کے دواوین کو
نذرآتش کردینے کا منظر دیکھا جاسکتا ہے۔ حالی نے شاعری کو جو اپنے منصب سے گر گئی
تھی نہ صرف اپنی شاعری کے ذریعے اس منصب تک واپس لانے کی کوشش کی بلکہ ’مقدمہ شعر
و شاعری‘ لکھ کر اسے سماجی زندگی میں ایک مناسب جگہ دلانے کا تہیہ کیا۔ انھوں نے
تصنع، مبالغے، ابتذال اور اخلاقی پستی کو نمایاں کرکے حقیقی شاعری کے لیے اصلیت،
واقعیت سادگی اور خلوص کو ضروری قرار دیا۔ اجتماعی زندگی اور سماج سے اس کے تعلق
کو ہی واضح نہیں کیا بلکہ مقدمے میں اس بات پر بھی زور دیا کہ شاعری کا ملکہ بیکار نہیں ہے، یہ قومی اور
اجتماعی زندگی کی تشکیل اور انسانی تہذیب کے فروغ کے لیے مؤثر حربہ ہے۔ شبلی کی
موازنہ انیس و دبیر یک طرفہ تنقید سہی لیکن اس کا بنیادی مقصد بھی پرتصنع شاعری کے
مقابلے میں حقیقی اور واقعی شاعری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اردو زبان میں علمی
اور ادبی نثر کے مختلف اسالیب کا فروغ بھی سرسید اور حالی کی تحریروں کا ہی مرہون
منت ہے۔
بعد میں ہمارے یہاں جن لوگوں نے تنقیدیں لکھیں ان میں
امداد امام اثر، وحید الدین سلیم، عبدالحق، عبدالرحمن بجنوری، مہدی افادی،
سرعبدالقادر، سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، حسرت موہانی، پنڈت دتاتریہ کیفی،
عظمت اللہ خاں، مسعود حسن رضوی، عبدالماجد دریابادی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی،
جعفر علی خاں اثر، ڈاکٹر یوسف حسین، ڈاکٹر عابد حسین، شیخ محمد اکرام، فراق
گورکھپوری اور دوسرے لوگوں کے نام آتے ہیں۔
ان تنقید نگاروں نے ایک طرف تو اپنے ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا، دوسری طرف مشرق و
مغرب کے ادبی اور تنقیدی اصولوں پر ان کی نظر تھی ان کے بارے میں یہ تو کہا جاسکتا
ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی بہت جامع اور ہمہ گیر شخصیت نہیں رکھتا اور نہ ہر قسم
کے ادب یا ہر قسم کے اسالیب سے عہدہ برآ ہونے اور اس کے ساتھ پورا انصاف کرنے کی
اہلیت رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کی نظر مشرقی ادب پر زیادہ ہے، مغربی ادب پر کم، بعض
مغرب سے زیادہ واقف ہیں لیکن مشرقی سرمائے سے ان کی واقفیت سرسری ہے۔ بعض قدیم کی طرف زیادہ مائل ہیں بعض کو جدید
سے لگاؤ ہے، بعض کسی صنف ادب کے دلدادہ ہیں تو بعض دوسری اصناف کے، لیکن ان سب میں
ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ ادب کی ادبیت کے منکر نہیں۔ اس لیے اپنے اپنے میدان میں
رہ کر انھوں نے جو کچھ لکھا اس سے ہمارے ادب کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچا اور
ہمارے شعور اور بصیرت میں اضافہ ہوا۔ ان تنقیدوں کے ذریعے ہم نے اپنے ماضی کے
شاعروں اور ادیبوں کو ازسر نو دریافت کیا اور ان کی قدر و قیمت متعین کی۔ نظیراکبرآبادی،
مصحفی، آتش، مومن اور غالب کی شاعری کی معنویت نمایاں طور پر سامنے آئی اور یہ
بھی کہ ماضی کے ان شعرا کے یہاں ایسے کون سے عناصر ہیں جو ہمارے شعور اور ہمارے
مزاج سے ہم آہنگ ہوسکتے ہیں۔ اردو غزل کے امکانات کا ازسر نو جائزہ لیا گیا، اس
کے مضر پہلوؤں کو ترک کرنے اور اس کے قابل قدر پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور انھیں
زندگی کے بدلتے ہوئے رجحانات سے عہدہ برآ ہونے کے قابل بنایا گیا۔ نثر میں نئے
نئے اسالیب اور نئی نئی اصناف اور ہیئتوں کے فروغ کا امکان پیدا ہوا۔ مغرب کے ادب
سے استفادے کا میلان آگے بڑھا، اس کے ساتھ سات اچھے اور قابل شعرا اور ادیبوں کی
عزت افزائی اور نااہل ادیبوں اور سستی شہرت کے طلب گاروں کی پردہ کشائی بھی ہوتی
رہی۔ اردو ادب اور شاعری میں اجتماعی اور قومی شعور، ہندوستانی تہذیب و معاشرت اور
ہندوستانی زندگی کے وسیع اور پیچ در پیچ مسائل کا عکس اور ادبی تحریروں کو اپنے
زمانے کے مطالبات پورا کرنے کے قابل بنانے کا ہنر آیا۔
1935
کے لگ بھگ ہمارے یہاں نئے ادب کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ
تحریک زبان و ادب میں اپنے ساتھ جو تبدیلیاں لائی اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، اس تحریک
میں نوجوان اور پرجوش ادیب تھے، باغی اور انقلابی تھے، ان کے اندر عزم و حوصلہ تھا
اور ان کا یہ جوش اور ولولہ، ان کی یہ بغاوت اور انقلاب پسندی بے معنی یا غیرفطری
نہ تھی، اس کے پیچھے سماجی عوامل اور محرکات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ساری بے
اعتدالیوں کے باوجود ہمارے ادب کو بعض اعتبار سے فائدہ پہنچا، زندگی کے بارے میں
حقیقت پسندانہ رویہ پیدا ہوا، رومانی اور خیالی ادب کی جگہ ایسے ادب نے جگہ لی، جو
انسانی مسائل سے آنکھیں چار کرسکتا تھا، افسانے اور ناول میں مواد اور ہیئت کے
اعتبار سے ایک جدید شعور پیدا ہوا اور مغربی ادب سے خاطرخواہ فائدہ اٹھانے کے
امکانات سامنے آئے، شاعری میں اسلوب اور
ہیئت کے اعتبار سے تازگی پیدا ہوئی، نفسیات کا علم گہرا ہوا، لیکن یہ ادبی تحریک
جو بعد میں دو گروہوں میں بٹ گئی، صالح اور متوازن تنقید سے محروم ہوگئی۔ جدید تنقید
کے یہ علمبردار ماضی کے تنقید نگاروں کو شارح اور مفسر کہنے لگے، ان کی تنقید کو
داخلی، رومانی، تاثراتی، اسلامی، ذوقی، وجدانی اور فنی تنقید وغیرہ کے نام سے یاد
کرنے اور انھیں حقیقی معنوں میں نقاد ماننے سے انکار کرنے لگے، ایسا کہنا بھی غلط
نہ ہوتا۔ اگر ہماری جدید تنقید پچھلی تنقیدوں کے تنگ دائرے سے نکل کر ایک وسیع اور
ہمہ گیر نقطۂ نظر پیدا کرتی اور نہ صرف ادب اور زندگی کے پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی
کوشش کرتی بلکہ فن پاروں کی تخلیق اور ادبی نوعیت پر نظر رکھتی۔ ہوا یہ کہ اس دور
میں جو نقاد سامنے آئے، انھوں نے ان تحریکوں کے مبلغ، وکیل اور مدافعت کرنے والے
کا منصب سنبھال لیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن کے اندر حس لطیف کی بے حد
کمی تھی یا انھوں نے اس کی مناسب تربیت نہ کی تھی، اس لیے شاعر اور متشاعر میں تمیز
کرنے یا ادب اور غیرادب کے فرق کو سمجھنے کا انھیں شعور نہ تھا۔ زندگی اور سماج کے
عوامل پر بھی ان کی نظر گہری نہ تھی۔ انھوں نے بعض نظریات اور بعض اصطلاحات کا
کتابی علم حاصل کرلیا تھا اس دور میں دو قسم کی تنقیدوں کو فروغ ہوا ایک تنقید
’ترقی پسند‘ یا مارکسی تنقید تھی، دوسری تنقید نفسیاتی اور ہیئتی تھی۔ ترقی پسند
تنقید نے پہلے ماضی کے سارے ادب سے روگردانی کی اور اسے جاگیردارانہ سماج کی یادگار
بتایا، اسے میر اور غالب کی شاعری فراری اور قنوطی نظر آنے لگی۔ جس کی طرف نظر
اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال اور ٹیگور رجعت پسند اور بیمار ادب کے
علمبردار سمجھے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان شعرا میں
انقلابی رجحانات تلاش کیے جانے لگے۔ چونکہ ادب اور غیرادب کی پہچان نہ تھی اورا س
کے تخلیقی عنصر کی پرکھ کا کوئی سلیقہ نہ تھا۔ اس لیے غالب اور میر کے وقیع اور
جاندار اشعار کو چھوڑ کر بعض رسمی، روایتی اور بے جان اشعار کی بنیاد پر ان کے
سماجی شعور کا تجزیہ کیا جانے لگا۔ تخلیقی ادب کے شعور کے اس فقدان کی وجہ سے ہم
عصر ادب سے بھی انھوں نے موضوعات کے بنانے کا کام شروع کیا، کسی شاعر نے اگر ہنگامی
واقعات اور سیاسی خیالات کو صرف نظم کردیا ہے اور کسی افسانہ نگار نے اشتہاری
اندازمیں بغیر فنی نزاکتوں اور تخلیقی عمل کی صعوبت اٹھائے اخبار کی خبروں کی بنیاد
پر موضوعات کی رپورٹنگ کردی ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک ادب ٹھہرا۔ اس قسم کے جائزوں
اور فہرستوں نے نااہل ادیبوں اور متشاعروں کو زیادہ اہمیت دے دی اور حقیقی ادیب و
شاعر نظرانداز ہونے لگے پھر صحت مند اور غیرصحت مند، مریضانہ داخلیت، بے لاگ خارجیت،
سماجی شعور، بین الاقوامی شعور، طبقاتی شعور، حقیقت نگاری وغیرہ کی اصطلاحات بھی میکانکی
طور پر استعمال کی جانے لگیں۔ ان اصطلاحات سے متعلق یا تو مضمون لکھے نہیں گئے یا
جو لکھے گئے وہ بے حد الجھے ہوئے تھے اور جو عملی تنقید یا جائزے لکھے جاتے تھے وہ
اس الجھن میں اور اضافہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کے زیراثر ہنگامی اور
صحافتی ادب کی پیداوار کثرت سے ہونے لگی جس نے بالآخر اس تحریک کو ادبی طور پر
بانجھ کردیا اس تحریک کے نمایاں اور صف اول کے شعرا کو وقت کے ظالم نقاد نے اپنی
کسوٹی پر رکھا تو اپنے سنگھاسن سے گرا دینے کے
لیے اور انھیں اس پر ایسی شرمندگی دامن گیر ہوئی کہ یا تو شاعری سے کنارہ
کشی اختیار کرلی یا بے ضرر قسم کی غزل گوئی میں پناہ لے لی جو شاعر حقیقی معنوں میں
شاعر تھے اور ترقی پسند خیالات سے بھی متاثر تھے۔ وہ اپنے طور پر شاعری کرتے رہے لیکن
نقادوں پر ان کا ایمان نہ رہا۔ حقیقی ادیب اور نقاد ایک دوسرے کے حریف اور دشمن نظر آنے لگے اور
ادیبوں کے حلقے میں پھر وہی خیالات دہرائے جانے لگے جو نقادوں کے بارے میں عام ہیں
یعنی ادیبوں کی راہ کا روڑا ہیں۔
نفسیاتی اور ہیئتی تنقید اگرچہ اتنی ہنگامہ خیز ثابت نہیں
ہوئی، اور نہ ہی اسے پسپائی کا یہ منہ دیکھنا پڑا لیکن اس نوعیت کی تنقید نے بھی
ابھی تک ہمارے ادب کو مثبت طور پر متاثر نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی
تنقید کے بیشتر علمبردار بھی ادب سے کم اور نفسیات کے اصولوں سے زیادہ واقفیت اور
دلچسپی رکھتے ہیں۔ انھوں نے فرائڈ، اڈلر اور ژونگ کے دیے ہوئے فارمولے تو ضرور سیکھے
لیکن یہ ہر کس و ناکس پر استعمال کیے جاتے
ہیں۔ جدید افسانہ اور جدید نظم میں سے ایسی چیزوں کو اپنے مطالعے کے لیے منتخب
کرنا جو تخلیقی ادب کا وقیع یا قابل قدر نمونہ نہیں ہیں اور ان کو پیش نظر رکھ کر
خواہ مخواہ فنکار کی نفسیات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش ایک طرح سے تضییع اوقات بن کر
رہ جاتی ہے۔ ویسے اس تنقید کے بعض نمونے اچھے بھی مل جاتے ہیں۔ ہیئتی تنقید والوں
میں بھی یہ عیب رہا کہ انھوں نے مواد اور ہیئت کے تخلیقی تعلق کو دیکھنے کے بجائے ہیئت کو مقصود بالذات سمجھ لیا، نتیجہ
یہ ہوا کہ ہر آزاد نظم یا ہر ایسی تجرباتی نظم قابل توجہ قرار پائی جو کسی تجربے،
احساس یا تخلیقی عمل سے وجود میں نہیںا ٓئی بلکہ ظاہری سانچے کی پابند ہے۔ فرانسیسی
انگریزی اور امریکی شاعروں کی نظموں کا اردو کے بعض ایسے شاعروں نے بھی چربہ اڑانے
کی کوشش کی جن میں بنیادی شعریات کا فقدان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید نظم اور آزاد
شاعری کو برگ و بار لانے کا پورے طور پر موقع نہ مل سکا اور متشاعروں کی نظموں نے
بعض لوگوں کو اس قدر بدظن کردیا ہے کہ وہ
اس طرح کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے حالانکہ بعض شعرا نے اس کو کامیابی
کے ساتھ برتا ہے۔
جدید اردو ادب میں جو انتشار و اختلال پیدا ہوا اور اس
کی صحیح سمتیں متعین نہ ہوسکیں اس کی وجہ ہمارے یہاں متوازن اور ہمہ گیر شخصیت
رکھنے والے نقادوں کی کمی ہے۔ پرانے نقاد نئے ادبی تقاضوں کو پورے طور پر نہ سمجھ
سکے اس لیے یا تو وہ نئے ادب کی مخالفت کرتے رہے یا خاموش رہے، بعض نئی اصناف اور
ہیئتوں کا شعور نہیں رکھتے تھے، اور اس معاملے میں اتنے قدامت پسند تھے کہ اسے بعض
مغرب زدگی سے تعبیر کرتے تھے، بعض جنس یا
سیاست کو ادب کے لیے شجر ممنوعہ سمجھتے تھے۔ غرض پرانے نقادوں کے اپنے حدود
تھے اور وہ نئے ادب سے عہدہ برآ نہ ہوسکے، اور اس سے پورے طور پر انصاف نہ کرسکے
تو اس میں ان کا زیادہ قصور نہیں، لیکن نئے نقادوں میں بعض اس کام کے اہل تھے۔ یہ
لوگ تنقید کے جدید اصولوں سے واقف تھے اور نئے عوامل اور محرکات کا بھی انھیں شعور
تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مختصر تنقیدی مضامین میں جدید ادبی و تنقیدی اصطلاحات
اور تصورات پر اشاروں اور کنایوں میں گفتگو کی یا پھر ہم عصر ادیبوں کی تصانیف پر
دیباچے اور پیش لفظ لکھ کر ان کے سرپرستی اور ہمت افزائی کرتے رہے۔ اس طریقہ کار
نے انھیں بھرپور تنقیدی کارنامے پیش کرنے کی مہلت نہیں دی، نئے ادب کے منفی عناصر
غالب آتے گئے اور ان حضرات کی تنقیدیں سمٹتی چلی گئیں۔ آخر مختصر تنقیدی مضامین
کے چند مجموعوں کے علاوہ ان حضرات نے کچھ نہیں دیا اور اب جب کہ اردو ادب کو ان کی
رہنمائی کی بے حد ضروری تھی یہ سب لوگ تبرک بن کر رہ گئے ہیں۔ سال دو سال میں کوئی
مختصر تحریر ان کے قلم سے نکل جائے تو اسے دعائیہ اور کلمۂ خیر سمجھیے۔
صورت حال یہ ہے کہ اس وقت تنقید کے نام سے بازار میںا یسی
چیزیں آرہی ہیں جو مدرسانہ یا مکتبی قسم کی ہیں، نقاد اب امدادی کتب تیار کررہے ہیں۔
یہ کتابیں ادب اور ادیبوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں، ان کے بارے میں
مختلف رایوں کو جمع کردیتی ہیں، ان کے خیالات کا خلاصہ تیار کردیتی ہیں۔ ان چیزوں
سے طلبا کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس سے ادبی تخلیق کے عمل میں کوئی مدد نہیں
ملتی۔ پھر یہ کتابیں ماضی کے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں ہوتی ہیں اور ان کی
نوعیت ماضی کے ادب کو زمانۂ حال کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے والی نہیں بلکہ تاریخی
اور تشریحی ہوتی ہے اس لیے وہ موجودہ دور کے ادیبوں کے مصرف کی نہیں۔ موجودہ دور
کا شاعر اور ادیب نئی زندگی کے مسائل اور ان کی پیچیدگیوں کو اپنے طور پر سمجھنے کی
کوشش کررہا ہے اس وقت اسے نہ نقاد کی رہبری حاصل ہے اور نہ اس کی رفاقت۔
رسالوں میں ایسے مضامین کی اب بھی بھرمار ہے جنھیں تنقید
کے ذیل میں درج کیا جاتا ہے لیکن یہ مضامین
زیادہ تر طالب علموں کے ہوتے ہیں جو ابھی زیرتعلیم ہیں اور ادب بھی ان کے نصاب میں
شامل ہے یا ان اساتذہ کے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں انھیں درس دیتے ہیں۔ ان مضامین
سے کلاس نوٹس کی بو آتی ہے۔ یہ مضامین پچھلی تنقیدوں کو الٹ پلٹ کرنے سے پیدا
ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ہمعصر ادب پر قلم اٹھاتے ہیں تو فہرست سازی، کھتونی
اور مردم شماری یا اقتباسات نقل کرنے سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی
تمام تنقید اچھی نثر کا نمونہ بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے کوئی نقاد یا مضمون نگار ایسا
نہیں جو اپنا طرز یا اپنی ادبی شخصیت رکھتا ہو۔ ادیبوں اور شاعروں کا حلقہ آج انھیں
ادیب کے زمرے میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قسم کی تنقیدیں تبلیغی یا مفتیانہ
تنقید کے مقابلے میں بے ضرر ہیں۔ لیکن ایسی تنقیدیں مستقبل کے ادب کی تعمیر و تشکیل
میں کوئی مدد نہیں دے سکتیں۔ بعض رسالوں میں ادبی مسائل پر بحثیں چلتی ہیں جو بہت
جلد ذاتی ہوجاتی ہیں اور تو تو میں میں کے اندر تبدیل ہوجاتی ہیں۔ بعض لوگ انھیں
کو اب تنقید سمجھنے لگے ہیں۔ غرض کہ اس وقت اردو میں نقاد کا لفظ ہنسنے ہنسانے کی
چیز بن کر رہ گیا ہے۔ نئے ادیبوں میں سے بعض کبھی کبھی تنقیدی مضمون لکھتے ہیں اور
ان میں خاصی تخلیقی اپج اور شعور ہوتا ہے لیکن موجودہ رجحان کو دیکھتے ہوئے ایسے
ادیب بھی اپنے آپ کو نقاد کہلوانا پسند نہیں کرتے اور نہ تنقید کو اپنے ادبی
مشاغل میں کوئی مستقل جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، کبھی کبھی اچھی کتاب یا ترشا ترشایا
مضمون نظر آجاتا ہے تو آس بندھتی ہے کہ شاید اب صالح تنقید اردو میں پیداہورہی
ہے۔ لیکن اس سے قبل لکھنے والا ادب کے مسائل پر توجہ کرے طومارنویسوں کے لگائے
ہوئے انبار میں وہ کتاب، وہ مضمون اور وہ نام گم ہوجاتا ہے۔
.ماخذ:
زاویۂ نگاہ، مصنف: خلیل الرحمن اعظمی، قیمت: 138 روپے، پہلی اشاعت: 2008، ناشر:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

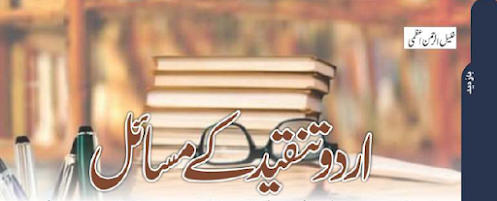




کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں