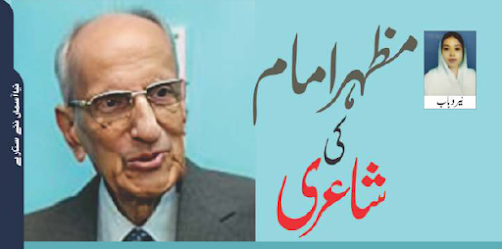اردو دنیا، مارچ 2025
بیسوی صدی سماجی،
معاشی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، اقتصادی ہر لحاظ سے بہت اہم صدی رہی ہے۔ عالمی سطح
پر بھی صدی میں کئی انقلابات رونما ہوئے۔ ہندوستان میں سیاسی سطح پر تقسیم کا
واقعہ پیش آیا۔ تاہم ادب میں بڑی تبدیلیاںواقع ہوئیں۔ اردوادب میں ترقی پسند تحریک،
حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے رجحانات اور نظریات نے ادب میں اسالیب،
زبان، موضوعات اور خیالات میں تبدیلیاں پیدا کیں۔
شاعروں اور افسانہ نگاروںکا ایک بڑا حلقہ سامنے آیا اور اپنی تخلیقات سے
اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔
مظہر امام کا شمار جدید غزل گو شاعروں میں کیا جاتا ہے۔
1943 کے آس پاس تیرہ چودہ سال کی عمر میں اپنی ادبی سفر کا آغاز کیا۔ترقی پسند
تحریک کے زیر اثر اپنے شاعری کی ابتدا
کرنے کے ساتھ ہی مظہر امام نے اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ان کے ابتدائی زمانے کے
کلام سے ہی ان کے ذاتی محسوسات و جذبات کی شدت اور انفرادی تجربہ اور مشاہدہ ان کے
ہم عصروں میں منفرد مقام عطا کرتا ہے۔تقسیم
کے بعد جدید شاعری کے آغاز کے زمانے میں جب ترقی پسندوں کا اثر کم ہوا اور
وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت مغربی افکارو
خیال کے اثرات اردو ادب پر پڑنے لگے تو اکثر ادیب اور فنکار اپنی فکر میں
تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ مظہر امام نے ہر چند کے کسی بھی تحریک یا نظریے سے خود کو
کبھی بھی مکمل طور سے وابستہ نہیںکیا۔ ان کے یہاں ہونے والی تبدلیاں ادب کے تقاضوں
کی غمازی ضرور کرتی ہیں۔ مظہر امام نے نہ
صرف نئی غزل کے حوالے سے شناخت قائم کی بلکہ اردو میں جو تنقیدی اور تاثراتی نوعیت
کے مضامین قلم بند کیے ہیں ان مضامین سے ان کے گہرے مطالعے اور مشاہدے ان کی تخلیقی
اور تنقیدی بصیرتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے شاعرانہ اسلوب نگارش نے آنے والے شعرا
کو متاثر بھی کیا ہے اور نئی نسل کے شعرا کے کلام میں ان کے اسلوب کی گونج صاف
سنائی دیتی ہے۔
مظہر امام نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا افسانہ نگاری سے
کی لیکن 1950 کے بعد افسانہ نگاری ترک کر کے شاعری کو اپنے افکار و خیالات کے
اظہار کا ذریعہ بنایا۔مظہر امام اپنی ادبی زندگی کے آغاز سے متعلق لکھتے ہیں:
’’میں
نے افسانہ نگاری اور شاعری اندازاً تیرہ سال کی عمر میں شروع کر دی تھی۔ یہ کہنے کی
ضرورت نہیں اس وقت کی غزلوں میں اکثر مصرعے ناموزوں ہوتے تھے اور افسانوں میں زبان
و بیان کی غلطیوں کے علاوہ بعض اوقات مضحکہ خیز غیرحقیقی واقعات ہوتے تھے۔ البتہ ایک
بات شاید دلچسپی کی ہو کہ اس وقت میری شاعری افسانہ نگاری کا محور حسن و عشق نہیں،زندگی
کے دوسرے موضوعات تھے اور صرف افسانوں میں ہی نہیں بلکہ اشعار میں بھی جذباتی
افلاطونی محبت کا مذاق اڑایا گیا تھا۔‘‘
(مظہر امام نئی نسل
کے پیش رو: مناظر عاشق ہرگانوی، نرالی دنیا پبلی کیشنز، 2003،ص 18 )
اس کے علاوہ مظہر امام کو شاعری کی طرف مائل کرنے میں اس وقت کے ادبا و شعرا نے بھی
اہم رول ادا کیا۔مظہر امام نے چونکہ شاعری کی ابتدا ترقی پسند تحریک کے زمانے میں
کی اس لیے ان کے یہاں ترقی پسند تحریک کے اثرات کا ہونا لازمی تھا۔ہر چند کہ مظہر
امام نے جدیدیت کے حوالے سے اپنی شناخت قائم کی۔ترقی پسند شاعروں اور دانشوروں نے
ادب کو زندگی کی ترجمانی کا وسیلہ قرار دیا۔
غریبوں،مزدوروں کے استحصال کے خلاف آوازاٹھانے کا جذبہ،سرمایہ داروں اور حاکم طبقوں کی مخالفت اس تحریک اور اس سے
منسلک دانشوروں کا اہم کارنامہ تھا۔انھوں نے ادب کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا،جس
نے عوام کے دکھوں کی ترجمانی اور ان کی زندگی کو دردو آلام اور مصائب سے نکال کر
خوشیوںکی راہ دکھانا اور تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔
بقول خلیل الرحمن اعظمی:
’’ہندوستانی ادیبوں
کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں ہونے والے تغیرات کو الفاظ اور ہیئت کا لباس
دیں اور ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لگانے میں ممدو معاون ثابت ہوں۔‘‘
(اردو
میں ترقی پسند ادبی تحریک: خلیل الر حمن اعظمی،ص 32)
سردار جعفری کا خیال ہے کہ
:
’’اس حقیقت کو پیش
نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ترقی پسند تحریک کا ایک بنیادی کردارہے اور ہماری ساری
جدوجہدیہ ہے کہ ہمارا ادب عوامی ادب بنے۔
(ترقی
پسند ادب:سردار جعفری، ص11)
مظہر امام کی غزلیہ شاعری کا ذکر ہو چاہے ان کی نظموں کی
بات چلے۔ ان کے متاخرین اور پیش رو شعرا اور ناقدین سبھی نے ان کے کلام کے حسن،ان
کے دلفریب اسلوب اور فکروفن پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کی انفرادیت کا اعتراف کیا
ہے۔
شمس الر حمن فاروقی ان کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں رطب
اللسان ہیں:
’’مظہر
امام کو اپنے لہجے کی انفرادیت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے
بلکہ حیات و کائنات سے ان کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کا تصور کسی روایتی فکر سے
وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ان کا کرب ان کا تجسس،ان کی برہمی، ان کی بے چارگی، پر
تفکرمحزونی ان عناصر کو الگ الگ کر کے دیکھیںتو یہ عصر حاضر کی عمومی فضامیں جگہ
جگہ مل جائیںگے۔ لیکن کسی شعری فکر کی انفرادیت نے ان مختلف دھاروں کو یکجاکر کے
انھیںاپنے کوزے میں بند کر لیا ہے اور یہی وہ نقشہ ہے جس میں کم تر درجے کے
شعرامات کھا جاتے ہیں۔‘‘ ( رابطہ،مظہر امام
نمبرص125)
جدیدیت کے زیراثر وجودی فکر کے تناظر میں مظہر امام کی
نظم ’ اشتراک‘ کا مطالعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
’’خیر
اچھا ہوا تم بھی میرے قبیلے میں آہی گئے
اس قبیلے میں کوئی کسی کا
نہیں
ایک غم کے سوا چہرہ
اترا ہوا بال بکھرے ہوئے
نیند اچٹی ہوئی
خیر اچھا ہوا تم
بھی میرے قبیلے میں آہی گئے
آئو ہم لوگ جینے
کی کوشش کریں ‘‘
ایک ودسری
نظم بہ عنوان’دھوپ میں ایک مشورہ ‘
اور تم
اپنے آدرش کی لاش کو
اجنبی، سرد، جلتی
ہوئی رہ گزر سے پرے پھینک کر
اپنا مفلوج غصہ لیے لوٹ آئوگے
پھر گڑ گڑاتی ہوئی التجا...
’
مجھ کو پہچاننے کی نہ کوشش کرو
!‘
ڈاکٹر وحید اختر نے لکھا کہ:
’’مظہر
امام کی نظمیں سیاست دوراں کو سمجھنے کی کوششوںسے بھی عبارت ہیں اور غم ذات و غم
جاناں کی آئینہ دار بھی۔ وہ آج کے ہر
سوچنے والے حساس ذہن کی طرح خود کو اپنے عہد میں اجنبی مانتے ہیں لیکن چونکہ یہی
احساس اجنبیت آج کے شعر و ادب کا سب سے اہم موضوع ہے، اس لیے وہ اپنے ہم عصروں کے درمیان نہیں۔نظمیں
ہو ں یا غزلیں دونوں ایک ہی دل و دماغ کی پیداوار ہیں۔‘‘
(زخم
تمنا: نئی شاعری کی ایک قابل مطالعہ مثال، ص 85-86)
مظہر امام کی غزلیں جدیدیت اور نئی غزل کے منظر نامے
پر بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی انفرادیت کی
نمایا مثال بھی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک مظہر امام کی شہرت و مقبولیت میں اضافے
کا سبب ہے ؎
اب تو کچھ بھی یاد نہیں ہے
ہم نے تم کو چاہا ہوگا
یہ آرزو تھی کہ یک رنگ ہو کہ جی لیتا
مگر وہ آنکھ جو شیطاں بھی ہے فرشتہ بھی
چیخوں کے ازدہام میں تنہا ہے آدمی
اے زندگی بتا کہ کدھر جارہی ہے تو؟
بیٹھیں کچھ دیر مہکتی ہوئی یادو ںکے تلے
شکر ہے آج ذرا کار جہاں بھی کم ہے
مظہر امام کی شخصیت ہمہ گیر ہے۔انھوںنے اردو شعروادب کی
جو خدمات انجام دیں، اس کا اعتراف کم وبیش تمام ناقدین نے کیا ہے۔مظہر امام کا
شمار یوں تو غزل گو شعرا میں ہوتا ہے مگر انھوںنے نظموں میں بھی اپنے قلم کے جوہر
دکھائے۔ساتھ ہی ساتھ آزاد غزل کاتجربہ کرکے بہت سی آزاد غزلیں بھی لکھیں۔اس کے علاوہ مظہر امام نے تنقید کے میدان میں بھی اپنی
شناخت قائم کی۔ابتدائی چھ دہایئوں کے طویل سفر میںان کی متعد دتصانیف منظر عام پر
آئیں۔ان کی شعری تصانیف میں پانچ کتابیں ہیںجو غزلوں، نظموں، خاکوں اور تنقیدی
موضوعات پر مشتمل ہیں۔
زخم تمنا، رشتہ
گونگے سفر کا، پچھلے موسم کا پھول، بند
ہوتا ہوا بازار، پالکی کہکشاں کی،اور سات کتابیں جو نثری
تصانیف پر مشتمل ہیں: آتی جاتی لہریں، ایک لہر آتی ہوئی، اکثر یاد آتے ہیں، آزاد غزل
کا منظر نامہ، جمیل مظہری، تنقید نما، نگاہ طائرانہ قابل ذکر ہیں۔مظہر امام کو ان
کی مجموعی ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات ملے۔1987میں ساہتیہ اکیڈمی ایواڈ
اور شعری مجموعہ ’ پچھلے موسم کا پھول‘1994،
غالب ایواڈ برائے اردو شاعری اہم ہیں۔
مظہر امام نے اپنی شاعری اور نثر کے حوالے سے جواثاثہ یادگار چھوڑا ہے وہ انھیں اپنے معاصرین میں نایاب حیثیت عطا کرتا ہے۔ غزل
اور نظم میں اپنی انفرادی شناخت قائم کرنے
کے علاوہ آزاد غزل کا تجربہ بھی مظہر امام کا اہم کارنامہ ہے۔ ان کی تنقیدی کتابیں
ان کے نظریات، رجحانات ان کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی پیش کرتی ہیں۔ ان کے لکھے
ہوئے خاکے،ادب کی اہم شخصیات کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔مختصر یہ کہ مظہر امام کی
شاعری اور فن اپنی مختلف خوبیوں کی بدولت ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں
گے ؎
یہ راہِ خار و سنگ مرا انتخاب بھی
جو مرحلے بھی آئے وہ حسب قیاس تھے
Nayyar Wahab
Research Scholar,
V.K.S University Ara- 802302 (Bihar)
Mob.: 9905244346
mahboobcam@gmail.com