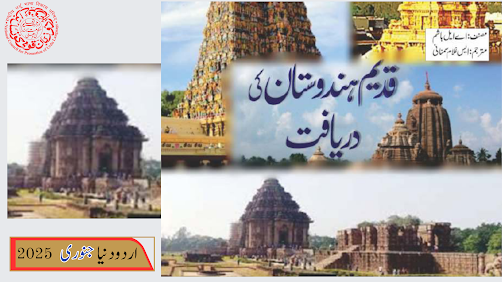اردو دنیا، جنوری 2025
دنیا میں کوئی بھی شاہکار اپنی تخلیق سے قبل جزوی طور
پر وجود میں آچکا ہوتا ہے اور وہ اس بات کی بشارت دے دیتا ہے کہ عنقریب کوئی ایک
ایسی شے کا وجود ہونے والا ہے جو انسان کی عقل کو متحیر و ششدر، تخیل کو حیران و
پریشان، فکر کو غلطاں و پیچاںاور فن کو پابوسی و قدم بوسی پر مجبور کردیتا ہے۔ میر
عطا حسین تحسین نے اگر ’نو طرز مرصع‘کو ’ قصہء چہار درویش ‘ نہیں بنایا ہوتا تو
کوئی میر امن اردو نثر کو ’باغ و بہار‘ کیسے بناتا۔ کوئی شیخ سعدی نہیں ہوتا تو
جلال الدین رومی اور حافظ و خیام کہاں سے آتے۔ اگر دہلی میں مغل حکمراںنصیر الدین
بیگ محمد خان ہمایوں کا تقریباً سترہ ایکڑ میں پھیلا ہوا مقبرہ تعمیر نہ ہوتا تو
شاہ جہاں کبھی اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں تاج محل جیسا شاہکار دنیا کو نہ دے
پاتا۔ اسی طرح اگر امتیاز علی تاج نے ’
انارکلی‘ جیسا لازوال ڈرامہ نہ تحریر کیا ہوتا تو کریم الدین آصف ’ مغلِ اعظم‘ جیسی
ایک شاہکار اور لازوال فلم دنیا کو نہیں
دے پاتا۔
امتیاز علی تاج کے اس فن پارے پر ’مغلِ اعظم ‘ فلم بننے
سے قبل ہی اس ڈرامے پر تین متعدد فلم سازوں نے فلم بنا ڈالی تھی لیکن جس طرح کی
جاندار، شاندار، شاہی جاہ و حشم اور تمکنت والی فلم کا خواب کے آصف نے دیکھا ویسا
آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے خواب فقط شہنشاہ ہی دیکھتے ہیں جو خواب کو زمین پر
اتارتے اتارتے فقیر یا درویش ہو جایا کرتے ہیں۔ تاج محل کو تعمیر ہونے میں اگر بائیس
برس لگے اور مغلیہ سلطنت نے اپنے خزانے لٹا دیے تو آصف نے بھی ’مغلِ اعظم‘ جیسے
عظیم کارنامے کو پورا کرنے میں چودہ برس لگا دیے اور آصف بھی اس فلم کو بناتے
بناتے فقیر اوردرویش ہوگیا۔
آصف نے مغلِ اعظم‘ کے علاوہ نہ کوئی اور خواب دیکھا
اور نہ کوئی خواب پالااور اس دوران اس عظیم خواب کی تکمیل میں جو رخنے اور اڑچنیں
آئیں اس کے نتیجے میں’پھول‘،’ محبت اور خدا‘،’ بھگت سنگھ‘ اور’ کلیو پیٹرا‘ جیسی
فلمیں بن گئیں۔اس دوران آصف اپنے واحد خواب ’مغلِ اعظم‘ کی تعبیر تلاش کرنے میں
کبھی بھی غافل نہیں رہے اور نہ ہی کسی اور فلم کو بنانے کا ایساعظیم، جاہ و حشمت
اور شاندار خواب پالا۔سوتے جاگتے ایک دیوانے کی طرح وہ ذرہ برابر بھی نہ تو اپنے
عزم مصمم سے ایک انچ پیچھے ہٹے اور نہ ہی اس نے ’ مغلِ اعظم‘ کو بنانے کا ارداہ
ترک کیا۔یہ فلم آصف کی زندگی اور کیریئر کے لیے گویا ایک ایسی فلم تھی جو اگر نہ
بنائی گئی تو گویا آصف کی زندگی رائیگاںاور عزم بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ کہا جاتا
ہے کہ آصف نے اس فلم کے پیچھے اپنا پورا کیریئر داؤں پر لگا دیا وہ بہت سگریٹ پیتے
تھے اور ایک وقت آیا جب وہ اُدھارکی سگریٹ پینے لگے۔ آصف نے ممبئی میں نہ تو
اپنا گھر بنایا اور نہ ہی کبھی کوئی گاڑی خریدی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فقیر
منش انسان نے دونوں ہی اشیا تادم مرگ کرائے پر رکھی شاید وہ درویشی کے ان جلی حروف
میں حد درجہ اعتماد رکھتا تھا کہ یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے انسان یہاں خالی ہاتھ
آیا ہے اور ہاتھ خالی ہی جائے گا بس اس کے اعمال و افعال ہی اس کو زندہ رکھیں گے۔
اس بابت جب ان سے پوچھا گیا کہ بمبئی میں آپ اپنا گھر کیوں نہیں بناتے تو اس دیوانے
کا جواب یہ تھا کہ’ میں یہاں فلمیں بنانے آیا ہوں گھر بنانے نہیں آیا ہوں‘۔
کے آصف نے ’مغل اعظم ‘ کاخواب غلام ہندوستان میں دیکھا
اور اس کو آزاد ہندوستان میں پورا کیا یعنی
ـیہ فلم تو اسی وقت تشکیل
پانے لگی تھی جب ’پھول‘ کی شوٹنگ کے دوران معروف فلم ساز کمال امروہوی نے ایک دن
امتیاز علی تاج کا لازوال ڈرامہ ’ انارکلی‘ کی کہانی سنائی۔اس کے بعد جیسے آصف کو
اپنا جہاں، اپنی منزل، اپنی تلاش، اپنی آرزو اور اپنی جستجو ہی مل گئی جس کے لیے
اسے قدرت نے بنایا تھا۔ کمال امروہوی اور کے آصف دونوں کی تعلیم بہت کم تھی لیکن
دونوں ہی فن کاروں میں ادب اور فلم پرزبردست دسترس اوریقین تھا۔ کے آصف کے متعلق
کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فلموں میں اداکاروں کے سامنے خود اداکاری کر کے بتاتے
تھے۔آصف بلا کا جادوگر تھا کسی بھی رئیس کے سامنے اگر وہ اپنی کہانی کی منظر کشی
پیش کر دے تو وہ اس کی کہانی سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتاتھا۔ یہی وجہ تھی
کہ اس نے ایک دن موقع محل دیکھ کر اپنے خواب کو مشہور فلم اسٹوڈیو ’ مہالکشمی‘ کے
مالک شیراز علی حکیم سے بیان کر ڈالا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب فلم میں پیسہ
لگانے کو راضی ہو گئے۔آصف اور شیراز علی کا مزاج ایک جیسا تھاجو بھی کام کرنا ہے
انتہائی اعلیٰ درجے کا کرنا ہے۔اس دور میں کہانیوں کا بادشاہ سعادت حسن منٹو بھی
بمبئی کی فلمی رعنائیوں میںگم تھا اس نے ایک جگہ آصف کی تعریف کرتے ہوئے اس کے
کہانی سنانے کے فن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ
:
’’
کہانی سنانے کے دوران وہ مداری پن کرتا ہے یعنی حسبِ
ضرورت واقعات کے اتارچڑھاؤکے ساتھ خود بھی چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ابھی وہ صوفے پر
ہے چند لمحات کے بعد وہ اس کی پشت کی دیوارپر، دوسرے لمحے اس کے سر کے نیچے
ہے اور ٹانگیں اوپر ہیںاور دھم سے نیچے
فرش پر۔ اس کے فوراً بعد وہ کرسی پر اکڑوں بیٹھا ہے مگر پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا
ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی ووٹ
حاصل کرنے کے لیے تقریر کر رہا ہے۔‘‘
فلم ’پھول‘ 1944میں ریلیز ہوئی اور اس کے بعد 1945میں
کے آصف نے مغل اعظم فلم کا آغاز کر دیا۔ یہیں سے اس فلم کو بنانے کی جدو جہد کا
بھی آغاز ہو جاتا ہے جتنی دلچسپ اور حیران کن یہ فلم ہے اس کے بننے کی کہانی بھی
اس سے کم دلچسپ نہیں ہے۔کہانی، اسٹار کاسٹ، کاسٹیوم، سیٹ، رقص، موسیقی، مکالمہ،
ہدایت کاری اور اداکاری غرض کہ کسی بھی پہلو پر آصف نے کہیں کوتاہی یا سمجھوتہ نہیں
کیا۔فلم کے ہر ایک شعبے پر دل کھول کر دولت لٹائی مگر اس فلم کے ریلیز ہوتے اس پر
اتنی پریشانیاں، افتاد، آپسی نااتفاقیاں اور مالی دشواریاں آئیںکہ ایسا لگا کہ
اب آصف کی کشتی غرقاب ہو جائے گی اور وہ ناچاہتے ہوئے کسی مالدار شخص کی دہلیز پر
دم توڑ دے گا مگر آصف کسی کے آگے جھکا نہیں۔وہ ایک ایسا درویش یا فقیر تھا جس کے
کشکول میںبعض دفعہ ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کا ہمالیائی ارادہ دنیا
فتح کرنے والا تھا۔’مغلِ اعظم‘فلم میں پیسہ لگانے والوں میں بامبے ٹاکیز کے مالک شیراز
علی حکیم سے لے کرشاپور جی پولن جی مستری جیسے بڑے تاجروں کا نام شامل ہے۔
شیراز علی حکیم سے ابھی آصف نے’ مغلِ اعظم‘ بنانے کا
قول و قرار کیا ہی تھا کہ اسی وقت بامبے اسٹوڈیو فروخت ہو رہا تھا جب یہ بات حکیم
صاحب تک پہنچی تو انھوں نے بامبے اسٹوڈیو خرید کر آصف کے حوالے کر دیا۔ بارہ
اکتوبر 1945کو جب اس فلم کی شوٹنگ کا شاہانہ انداز میں شُبھ مہورت ہو رہا تھا اس
وقت اکبرِ اعظم کے رول میں چندر موہن،مہارانی جودھا بائی کے روپ میں درگا کھوٹے،
شہزادہ سلیم کے رول میں سپرو اور انارکلی کے طور پر نرگس کو سائن کیا گیا تھا۔فلم
کی کہانی میں بھی آصف نے اپنے انداز ِ فکر ونظر کے اعتبار سے تھوڑی بہت تحریف کی
تھی یعنی ڈرامہ انارکلی کی کہانی سے کچھ اجزا نکال کر کچھ نئے اجزا کا اضافہ کر دیا۔سید امتیاز علی تاج کے شہرۂ
آفاق ڈرامے’ انارکلی‘ میں اکبر، سلیم، بختیار (سلیم کا بے تکلف دوست)رانی، انارکلی، ثریّا، دل آرام اور زعفران جیسے کردار موجود ہیں
جبکہ فلم میں بختیار کے کردار کی جگہ درجن سنگھ اور دل آرام کی جگہ پر بہار کا
اضافہ کیا گیا ہے۔
فلم کو مزید پرکشش اور
مربوط بنانے کے لیے اس کہانی میںپلاٹ، کردار، مکالمے وغیرہ میں حسبِ ضرورت تبدیلی
کیے گئے۔ابتدائی فلم یعنی 1951 سے قبل والی ’مغلِ اعظم‘ میں انارکلی کے رول میں
نرگس اور بہار کے طور پر وینا کو منتخب کیا گیا مگر جیسے ہی ہندوستان کو آزادی حاصل
ہوئی اور ملک تقسیم ہوا اور اس کے بعد جو خونیں واقعات رونما ہو ئے اس نے تاریخِ
انسانیت کو لرزاں، حیراں اور پریشاں کر دیا۔اس عالمِ بے سروسامانی میں بہت سے خانہ
بدوش ہجرت کر کے پاکستان سے ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان چلے گئے۔ کپور
خاندان اور چوپڑہ خاندان جیسے نہ جانے کتنے ہی خاندان سرحد کے اُس پار سے اِس پار
بے سرو سامانی کے عالم میں آئے اسی طرح سعادت حسن منٹو، شیراز علی حکیم، جوش ملیح
آبادی اور آصف کے ماموں نذیراحمد خاں بمبئی کو خیر باد کہہ کر پاکستان آباد
کرنے چلے گئے۔ اس عظیم سانحے کا اثر نہ صرف یہ کہ نوجوان آصف کے ذہن و دل پر ثبت
ہوا بلکہ اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ کیونکہ کے آصف جب بمبئی آئے
تو اپنے ماموں نذیر جو اس وقت فلموں میں ایکٹر تھے انھیں کے یہاں ٹھہرے اور ان کے
ماموں نے آصف کو فلموں میں ڈریس سپلائی کرنے والے ایک ٹیلر کے یہاں سلائی وغیرہ
کا کام سیکھنے کے لیے رکھ دیا۔یہیں سے آصف کو اپنی منزل کا پتہ اور راستہ مل گیا۔
آصف فلموں کے شیدائی تو تھے ہی مگر اسی بہانے ان کو فلموں کی ایکٹنگ،شوٹنگ اور میکنگ
کو بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا اور آصف کے فن کو بال و پر عطا
ہو گئے۔ آزادی کے بعد جیسے ہی ملک تقسیم ہوا تو آصف کے ماموں نذیراحمد خان نے
بمبئی چھوڑ کرپاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ اس وقت تک نذیر ایک کامیاب
اداکار کے طور پر انڈسٹری میں اپنے پیر جما چکے تھے۔آصف کے پاس بھی موقع غنیمت
تھا کہ وہ پاکستان چلا جاتا مگرکے آصف کو تو ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر و تشکیل
کرنا تھا جو ہزار زخم کھانے کے بعد، قتل و خون کے دریا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی دیرینہ
صلحِ کل کی روایات، مساوات، اخلاقیات و نظریات پر باقی رہ سکے۔ حالات کے سامنے
سرنگوں ہونا تو آصف کے مزاج کا حصہ ہی نہیں تھا۔ آزادی اور بٹوارے کے بعد بھی وہ
جس طرح کے ہندوستان کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے پھر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ دیگر
سیکولر مزاج اور امن پسند شہری بھی اس کے خواب میں شامل ہو جائیں کیونکہ آصف کے
خوابوں والے ہندوستان کی تکمیل تو بس بمبئی فلم انڈسٹری میں ہی ہو سکتی تھی۔ آصف
تو ایک ضدی مزاج انسان تھا ایک دفعہ جس کام کو اس نے ٹھان لیا تو بس اسے ہر حال میں
ممکن بنا کر ہی دم لینے والوں میں سے تھا۔ابھی ’مغلِ اعظم‘ کی شوٹنگ ہوئے دیر بھی
نہیں ہوئی تھی کہ بٹوارہ سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور فلم متاثر ہو گئی۔شوٹنگ
روکنی پڑ گئی اور اتنی شاہانہ فلم جس پر پانی کی طرح پیسا لگا ہو وہ تقسیم کے خونیں
سیلاب میں غرقاب ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ جب آگ اور خون کا یہ دریا اپنی طغیانی
پر پہنچنے کے بعد کچھ تھما تو آصف نے اپنے خوابوں کی کشتی پھر سے دریا میں اتاری۔اپنے
ریزہ ریزہ خوابوں کو سمیٹتے ہوئے پھر سے تنکا تنکا جوڑنا شروع کیا اور کئی برس سے
آنکھوں میں بند پڑے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش اور جستجو میں غرق ہو گیا۔
ملک کی آزادی اور تقسیم
کے خونیں مناظر کے بعد آصف نے فلم’مغلِ اعظم‘ کی اسکرپٹ پر نظر دوڑائی تو وقت اور
حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ اب کہانی میں خاطر خواہ تبدیلی کی جائے جس سے ملک کی
تقسیم سے پیدا ہونے والے گہرے زخموں کا نفسیاتی علاج اس طرح کیا جائے کہ دوقوموں
کے درمیان وہی پرانا اعتماد اور وقار پھر سے بحال ہو جائے۔جہاں ایک طرف آصف کہانی
میں کچھ تبدیلی کر رہے تھے وہیں کچھ پرانے اداکاروں نے آصف کا ساتھ چھوڑ دیا۔
قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اکبِراعظم کا کردار نبھانے والے چندر موہن اچانک اس
دنیا سے رخصت ہوگئے اور تو اور شہزادہ سلیم کا رول اداکرنے والے سپرو بھی اپنی
پرانی چمک دمک کھو کر اب معاون اداکار کے بطور فلموں میں نظر آنے لگے تھے۔فلم کی
ایک چوتھائی شوٹنگ بھی ہو چکی تھی جو لوگ فلموں کے مختلف مراحل سے واقف ہیں وہ
بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے نازک وقت میں قدم پیچھے کھینچنے کا مطلب خود کو کتنے طرح
کے خسارے میں مبتلا کرنا ہے۔اکبرِاعظم اور شہرزادہ سلیم دونوں ہی اگر اپنی چمک دمک
کھو دیں تو فلم میں بچتا ہی کیا ہے۔کوئی اور ہوتا تو اپنے ہی خواب کو اپنی آنکھوں
کے سمندر میں غرقاب کردیتااور فلم سازی سے توبہ کر لیتا مگر آصف نے دل پر پتھر
رکھ کر اپنے تخلیق کردہ نامکمل مجسمے کو بڑی ہی نامرادی اور مایوسی کے ہتھوڑے سے
توڑ ڈالااور ایک نیابت تراشنے کے بارے میں سوچنے لگا۔کولمبس کے مانند وہ اپنی کہانی
کے کرداروں کی تلاش میں نکل پڑااور ایک مقام پر اسے اپنے وقت کے عظیم اداکار پرتھوی
راج کپور میں اکبر ِاعظم تلاش کرلیا، مہہ جبیں عرف مدھوبالا میں انارکلی اور
شہنشاہ جذبات دلیپ کمار المعروف یوسف خان میں شہزادہ سلیم کو دریافت کر لیا۔ اب ان
سب کو لے کر دوبارہ فلم کی شوٹنگ شروع کی اور جب فلم مکمل بن کر سامنے آئی تو دیکھنے
والے نے آصف کے ہندوستان کی وہ عبارت پڑھ لی جو آزادی اور بٹوارے کے بعد
ہندوستان کی پیشانی پر آصف نے جلی حروف میں تحریر کیا تھا وہ یوں بیاں کی :
’’میں
ہندوستان ہوں، ہمالیہ میری سرحدوں کا نگہبان ہے، گنگا میری پوِترتا کی َسوگندھ،
تاریخ کی ابتدا سے میں اندھیروں اور اجالوں کا ساتھی ہوں اور میری خاک پر سنگِ
مرمر کی چادروں میں لپٹی یہ عمارتیںدنیا سے کہہ رہی ہیں کہ ظالموں نے مجھے لوٹا
اور مہربانوں نے مجھے سنوارا، نادانوں نے مجھے زنجیریں پہنا دی اور میرے چاہنے
والوں نے انھیں کاٹ پھینکا۔میرے ان چاہنے والوں میں ایک انسان کا نام جلال الدین
محمد اکبر تھا‘‘
ایسا نہیں ہے کہ امتیاز علی تاج کے ڈرامے پر آصف نے
کوئی پہلی مرتبہ فلم بنانے کی ٹھانی بلکہ آصف سے پہلے بھی اس کہانی پر کئی فلمیں
بن چکی تھیں۔نند لال جسونت لانے 1953میں ’ انارکلی‘ کے نام سے فلم بنا ڈالی۔زیادہ
تر فلم سازوں نے محبت کی اس لازوال داستان کو ہی اپنی کہانی کا مرکز بنایا مگرکریم
الدین آصف نے مغلیہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ اکبرکو مرکز میں رکھ کر کہانی کے در و
بست اس طرح سنوارے کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کی داستان بھی رنگینی اختیار
کر لے۔ڈرامے میں ان تبدیلیوں کے لیے اس نے اپنے وقت کے مشہور و معروف قلم کاروں کی
ایک ٹیم لگا دی جس میںکمال امروہی،وجاہت میرزا چنگیزی، احسن رضوی اور امان صاحب جیسے
لوگ شامل تھے۔اس کے علاوہ خودآصف بھی اس مکالمہ نگاری کی ٹیم کا حصہ تھے۔ان سب کی
مشترکہ کوششوں سے فلم کی جو کہانی نکل کر باہر آئی اسے اگر ایک الگ ہی قسم کی کہانی
کہاجائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی جس نے مغلیہ تاریخ کے بہت سے حقائق کو چیلنج کیا
ہے۔شہزادہ سلیم، انارکلی، بہار، درجن سنگھ، سنگ تراش جیسے لازوال کردارتو تاریخ کی
کترنوں سے نکل کرعوامی حافظے کا ایک ایسا حصہ بن گئے کہ جس کے نقوش کو مٹانا آسان
نہیں ہے۔اس مرکب کہانی میں لیلیٰ مجنوں کی افسانوی داستان، رادھا کرشن کی پریم
کتھا،راجہ دشرتھ کا کیکئی کو وچن،جہاں گیر کا انصاف،مہابھارت، الف لیلیٰ اور ہماری
اساطیری کہانیوں کی زیریں لہریں ہمارے اوپر اس قدر اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی
ہیں کہ ایسی کہانی بننے والا ابھی تک کوئی دوسرا شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔کہانی کی
پرتوں کو اجاگر کرتے ہوئے راجکمار کیسروانی اپنی کتاب ’داستانِ مغلِ اعظم‘ میں ایک
جگہ کہتے ہیں کہ :
’’
اوپر اوپر سے یہ ایک سہہ رخی عشقیہ داستان ہے جس میں
باقاعدہ عاشق (شہزادہ سلیم) معشوق (انارکلی) اور رقیب (بہار) جیسے کردار ہیں، لیکن کہانی میں اکبرِ
اعظم کے کردار کوکہانی کے مرکز میں لا کر آصف نے کہانی کو ایک نیا نہج دے دیا ہے۔
محبت کی اس داستان میں نسلوں کی سناتن جد و جہد، ایک شہنشاہ کی شہنشاہ بن کر ہر چیز
کو دیکھنے کی مجبوری اور ماں کی مامتا پر مہارانی جودھابائی کا مہارانی کے عہدے کو
نچھاور کرتے جذبات، کہانی کو اپنے مقامِ عروج پر لے جاتے ہیں۔
کے آصف نے امتیاز علی
تاج کا شہرۂ آفاق ڈرامہ ’ انارکلی‘ کی کہانی کو ایک ایسی کہانی کے روپ میں تبدیل
کیا جس میں مرکزی کردار انار کلی کی جگہ اکبرِ اعظم کو فوقیت دی اور تمام تر کہانی
اسی کے ارد گرد تخلیق کی۔اس وقت کے دیگر ہدایت کاروں نے انارکلی بنائی جب کہ اسی
کہانی پر آصف نے ’ مغلِ اعظم‘ بنائی جو ایک ایسی لازوال کہانی بن گئی جس کے بعد
کوئی دوسری عشقیہ داستان جچتی ہی نہیں۔اگر چہ اس عہد کی عکاسی کے لیے اردو فارسی
زبان کا خوب استعمال کیا گیا ہے جو کسی بھی صورت میں فلم بین پر قطعاً گراں نہیں
گزرتی بلکہ عام فلم بین اس زبان کی چاشنی سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے۔ فارسی اور
اردو کے الفاظ و تراکیب، مثلاً تخلیہ، جنبش مکن، بنام تاجدارِ ہندوستان،ملکہء ذیشان،
زینتِ تختِ ہندوستان مہارانی جودھابائی، شہزادہ نورالدین محمد سلیم وغیرہ عام قاری
کے ذہن و دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ہر چند کہ یہ بڑے ہی ثقیل الفاظ و تراکیب ہیں لیکن
مناظر میں استعمال ہو کر یہ اپنے معنی و مفہوم خود بہ خود بتا دیتے ہیں۔ اس فلم کا
ایک ایک مکالمہ آج بھی عوام کے درمیان گردش کر رہا ہے۔کس مکالمہ نگار نے کون سا
مکالمہ تحریر کیا ہے اس کابھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ہاں اس کی اسکرین پلے
سے متعلق کئی دلچسپ معلومات ضرور ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فلم کے ایک سین
میں جب انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوانے کا منظر لکھا جارہا تھا تو آصف نے سب کو
کہا کہ کوئی ایسا مکالمہ تحریر کریں کہ جس سے کم الفاظ میں ساری باتیں کہہ دی جائیں
تو سب اپنے اپنے انداز میں مکالمہ لکھ کر لائے آصف صاحب بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سب
کے ڈائیلاگ سن رہے تھے۔ آخر میں جب وجاہت مرزا کا نمبر آیا تو ان سے آصف نے
پوچھا کہ آپ کیا لکھ کر لائے ہیں۔مرزا نے اپنے پاندان سے ایک پرچی نکالی اور کہا
کہ اس منظر میں انارکلی محض ایک جملہ ادا کرے گی۔ سین کی وضاحت کرتے ہوئے وجاہت
مرزا نے کہا کہ انارکلی پہلے شہنشاہ اکبر کو سلام کرے گی اور کہے گی
انارکلی: یہ
ادنیٰ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے۔
اس جملے پر پورے کمرے کا ماحول مشاعرے جیسا ہو گیا ہر
طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی اور سب نے اسی ڈائیلاگ پر اپنی ہامی بھر دی۔فلم
کی کہانی کا انجام بھی بڑا دلچسپ ہے جس میں انارکلی کو زندہ دیوار میں چنے جانے کا
حکم دیا جاتاہے مگر اکبر اپنے لاڈلے شہزادے سے تمام تر اختلافات کے باوجود، انارکلی
کی شکل سے نفرت کے باوجود اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے
کہ انارکلی مغل سلطنت کی خفیہ سرحدوں کو پار کر کے کہیں اور چلی جائے اور یہ راز کہ انارکلی زندہ ہے ہمیشہ کے لیے ایک
راز ہی رہ جائے تاکہ اس بات سے شہزادہ سلیم مطمئن ہو جائے کہ انارکلی مر چکی ہے۔اکبر کے کردار کو عظیم اور اعلیٰ
قدروںکا ایک بڑا کردار بنا نے کے لیے آخر
میں اکبر انارکلی سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ
:
اکبر: انارکلی ! جب تک یہ دنیا قائم رہے گی
تم لفظِ محبت کی آبرو بن کر زندہ رہو گی...
اور مغلوں کی تاریخ تمھارا یہ احسان یاد رکھے گی کہ تم نے بابر اور ہمایوں کی نسل
کو نئی زندگی دی۔ لیکن ہم تمھیں ایک گم نام زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ہم
مجبور ہیں۔ بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں اپنے اصولوں کے غلام ہیں، ایک غلام کی بے بسی
پر غور کروگی تو شاید تم ہمیں معاف کر سکو۔‘‘
حواشی
1 راج
کمار کیسوانی، داستانِ مغل اعظم(ہندی)، منجُل پبلشنگ ہاؤس، بھوپال، 2020
2 امتیاز
علی تاج، انارکلی، اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ، 1997(تیسرا ایڈیشن
3 مغلِ
اعظم(فلم)، ہدایت کار کے آصف، 1960
Muntazir Qaimi
Dept of Urdu
Fakhruddin Ali Ahmad Govt P G College
Mahmudabad (Awadh)
Sitapur - 261203 (UP)
Mob.: 8127934734
muntazirqaimi@gmail.com